دوسرا باب
عدل
ہم شیعوں کاعقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے اور صفت عدل، خدا کی صفات جمالیہ سے ہے عدل الٰہی کا عقیدہ نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عدل الٰہی کے عقیدہ کا تعلق ایک طرف تو خدا پر ایمان رکھنے سے مربوط ہے اور دوسری طرف قیامت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ایک طرف مسئلہ نبوت و امامت نیز احکام کے فلسفہ اور جزاء و سزا، جبر و تفویض کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے لذا اگر اصل عدالت کو نہ مانا جائے تو سب اعتقادات اسلامی مخدوش نظر آئیں گے۔
مسئلہ عدل کا تاریخچہ
اگرچہ سب فرق اسلامی خدا کی عدالت کے قائل ہیں لیکن عدالت کے معنی اور تفسیر میں اختلاف رکھتے ہیں اہل سنت کا ایک گروہ اشعری ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ خدا سب ہستی کا مالک ہے جو کام بھی کرے(خواہ نیک اور پرہیزگاروں کو جہنم میں ڈال دے اور بُرے اور بدکاروں کو جنت میں بھیج دے) یہ عین عدالت ہے۔
اس گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے افعال کے بارے میں حسن و قبح نہیں ہے جو وہ انجام دے وہ اچھا اور نیکو ہے اس گروہ کا رئیس ابو الحسن اشعری ہے جو کہ ابو موسی اشعری کی نسل سے تھا۔
اس عقیدہ کی پیدائش کا انگیزہ کیا ہے؟ اس کا انگیزہ یہ ہے کہ چونکہ اشعری جبر کے قائل تھے یعنی اس گروہ کا عقیدہ یہ تھاکہ انسان اپنے فعل میں خودمختار نہیں ہے بلکہ مجبور ہے جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہ خدا کے ارادہ سے ہے۔
تو اس نظریہ پر جب یہ اعتراض ہوا کہ جب انسان اپنے افعال میں مجبور ہے اگر انسان غلط اور برے کام کرتا ہے تو (نعوذ باللہ) یہ خدا کی خواست سے انجام دیتا ہے تو پھر خدا، انسان کو برے کام پر سزا کیوں دے گا۔ بعبارت دیگر جب برے کام خود ہی کرواتا ہے تو پھر سزا کا کیا مطلب ہے؟ لذا اس گروہ سے جب اس اعتراض اور سوال کا جواب نہ بن پایا تو عدل الٰہی کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ خدا جوکام بھی کرتا ہے وہ عین عدالت ہے۔
عقیدہ حق کون ساہے؟ کیا عقل اچھائی اور برائی کو درک کرسکتی ہے؟
حق بات یہ ہے کہ انسانی عقل حسن و قبح اور اچھائی وبرائی کو ادراک کرسکتی ہے چونکہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ جس کے ذریعہ سے ہی وہ توحید اورنبوت کا اثبات کرتا ہے اور اگر عقل کی ذاتی صلاحیت کے منکر ہوجائیں تو پھر معرفت الٰہی اورمعارف اسلامی کی پہچان اور تصدیق کیسے ممکن ہوگی؟ ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ عدل (عدالت) اچھی چیز ہے ظلم قبیح اور بری چیز ہے۔ احسان کرنا، سچ بولنا، امین ہونا یہ اچھی چیزیں ہیں۔ جھوٹ، خیانت، دھوکہ، چوری، حسد، کینہ، جہالت، بے جا غضب وغیرہ یہ بُری چیزی ہیں۔
پس معلوم ہوا کہ عقل، حسن و قبح کو درک کرسکتی ہے ، ہاں انسان کی معلومات چونکہ محدود ہیں انبیاء کی بعثت سے ادراکات عقلی کو تائید بھی ہوگئی اور جن امور کے ادراک عقلی میں اپنی محدودیت کی وجہ سے ناتوانی پائی جاتی تھی وہ بعثت انبیاء سے ظاہر اورآشکار بھی ہوگئے۔
خدا کیوں عادل ہے؟
کیونکہ عدل، صفت کمال ہے اور خداوند متعال سب کمالات کا مالک ہے۔ کیونکہ وہ اپنے عدل کی خبر دے چکا ہے۔
کیونکہ پوری مخلوقات کا انتظام اس کے عدل کا مقتضی ہے۔
کیونکہ عدل کےمقابلے میں ظلم ہے اور ظلم ، ہر عاقل کے نزدیک برا ہے اور خدا ہر برائی سے منزہ اور پاک ہے لہذا وہ ظالم نہیں ہوسکتا پس وہ عادل ہے۔
کیونکہ ظلم وہ کرتا ہے جو عدل کے انجام دینے سے عاجز ہو یا ظلم کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو خدا عجز سے منزہ ہے بعبارت دیگر ظلم احتیاج اور ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور ذات حق تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔
کیونکہ اس نے اپنے آپ سے ظلم کی نفی کے ہے{ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ }([1]) خدا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ پس وہ عادل ہے۔
تذکر: مخفی نہ رہےکہ حق تعالیٰ تکوینیات میں بھی عادل ہے، تشریعات اور جزاء دینے میں بھی عادل ہے۔و التفصیل فی محلہ۔
مصیبتوں اور دردناک حوادث کا فلسفہ
سوال:جب خدا عادل ہے کہ حقاًٍ عادل ہے توپھر بعض کامصیبتوں میں مبتلا ء ہونا، یا اپنے اہداف میں ناکام ہونا، بیمار ہونا، یا ناقص الخلقت ہونا، نابینا پیدا ہونا یا گونگا ہونا یا بہرا اور مفلوج ہونا وغیرہ یہ سب چیزیں عدل الٰہی کے ساتھ کیسے سازگار ہوسکتی ہیں؟
جواب: جب یہ بات عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ، حکیم و عادل ہے کوئی کام بغیر حکمت کے انجام نہیں دیتا تو معلوم ہے کہ مذکورہ امور میں کوئی نہ حکمت ضرورت ہے اور اگر ہم ان امور کی حکمت کو نہ جان سکیں تو یہ ہماری آگاہی کی محدودیت ہے۔
البتہ مخفی نہ ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہیں جن کا موجب اصلی خود انسان ہے مثلاً انسان اپنے امور میں سستی و غفلت کرے محنت اور کوشش نہ کرے، یا اگر کوئی طالب علم درس نہ پڑھے اور محنت سے کام نہ لے تو اب اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ خود اس کی اپنی طرف سے ہے یا مثلاً کوئی شخص گلی سڑی غذا کھائے تو اس کے اثر میں بیمار ہوجائے تو یہ بھی اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوا ہے۔ یا مثلاً جو نظم و ضبط سے کام نہیں لیتا تو اس وجہ سے اگر کوئی پریشانی لاحق ہوجائے تو یہ بھی اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔
یا مثلاً اگر والدین (نکاح اورجماع) کے بارے میں اسلامی دستورات کی مراعات نہ کریں تو اس کے اثر میں اگر بچہ ناقص الخلقۃ پیدا ہوجائے ، اگرچہ بچہ بے قصور ہے لیکن اس کے والدین کے ظلم وجہل کی وجہ سے بچے پر طبیعی اثرات کی وجہ سے وہ ناقص پیدا ہو تو اس کا مواجب اس کے والدین بنے ہیں۔
لیکن معصومین علیہم السلام کیطرف سے اس طرح کےنقص کی روک تھام کے لیے فرمودات نقل ہوئے ہیں کہ کن کن عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے اور کن کن اوقات میں جماع سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اولاد ناقص الخلقہ نہ ہو۔ بلکہ روایات میں ان امور کا بھی ذکر آیا ہے کہ جن کی رعایت سے بچہ خوش استعداد اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے ۔ ان شئت التفصیل فراجع الی مظانہ۔
لہذا ناکامیوں، مصیبتوں اور اس طرح کی بلاؤں کا موجب خود انسان یا دیگر لوگ ہیں ان کو خدا کے حساب میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔
چنانچہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے:
{ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}([2]) تم تک جواچھائی اورکامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اورجو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔
اور پھر ارشاد رب العزت ہے:
{ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}([3])
اورلوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بناء پر فساد خشکی اور تری ہرجگہ غالب آگیا ہے تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آجائیں۔
مخفی نہ رہے کہ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے حکمت، مصلحت اور عدالت کے مطابق کرتا ہے کیونکہ وہ حکیم و عادل ہے فعل قبیح اور ظلم اس کی ذات سے محال ہے عدل کے متعلق بہت سے اشکالات، جہالت ، وقائع اور مصائب کے فلسفہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ مثلاً جس نے یہ خیال کیا کہ موت ختم ہوجانے کا نام ہے تو پھر یہ اشکال کردیا کہ فلاں جوان شخص کیوں مر کرگیا یا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کہ زلزلہ اور تباہ کن سیلاب کیوں آئے جس سے اتنے نقصانات ہوئے۔
یا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا آسائش کی جگہ ہے تو پھر اعتراض کر دیا کہ وہ گروہ کیوں محروم ہیں حالانکہ اگر دنیا اور اس کی خلقت کے مقصد کی پہچان ہوجائے تو بہت سے اشکالات ختم ہوجاتے ہیں۔
نزول بلیات اورمصائب کی وجوہات
- 1.ممکن ہے بلاؤں کا آنا سزا کی وجہ سے ہوجیسا کہ گذشتہ کئی قوموں کانابود ہونا۔ { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}([4]) اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف ، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور میوؤں کی کمی سے آزمائیں گے اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔
- 2.ممکن ہے امتحان کی وجہ سے ہوں۔
- 3.ممکن ہے تربیت نفوس و تکمیل درجات کی وجہ سےہوں بعبارت دیگر انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہوں۔
- 4.ممکن ہے گناہوں کے کفارہ اور تخفیف عذاب کی وجہ سے ہوں جیسا کہ کئی ایک احادیث سے مستفاد ہے۔
- 5.ممکن ہے قیامت کے دن بلندی درجات کی وجہ سے ہوں۔
- 6.ممکن ہے کسی اور وجہ سے ہوں جن کو ہماری ناقص عقل نہ سمجھ سکتی ہو۔
خلاصہ یہ کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بے مثل و مثال ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں جاسکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
مجسمہ اہل سنت کا ایک گروہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے (العیاذ باللہ) خدا کے ہاتھ ہیں، پاؤں، اور دیگر اعضاء و جوارح ہیں ،وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور چار چار انگلی عرش سےباہر ہے ، اور وہ جمعہ کی رات کو اوپر سے نیچے چوتھے آسمان پر اترتا ہے، جب طوفان نوح آیا تو مخلوق کے غرق ہوجانے پر کفار و مشرکین کی ہلاکت پر شدید گریہ کیا حتی کہ اس کی آنکھیں خراب ہوگئیں۔
رسول خدا ﷺ نے معراج کی رات خدا کو جوانی کی حالت میں دیکھا۔
قیامت کے دن خدا کرسی پر بیٹھے گا اور کرسی چڑچڑائے گی، قیامت کے دن خدا مومن لوگوں سے مصافحہ کرے گا۔
قیامت کے دن خدا اپنا قدم جہنم میں رکھے گا اور جہنم کہے گی کہ اب میں بھر گئی ہوں۔
جہنم میں قدم رکھنے والی روایت، اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ توحید ۔
قضاء و قدر
قضاء کے لغت میں بہت معانی ذکر ہوئے ہیں: ۱۔ خلق کرنا، ۲۔امر، ۳۔اعلام، ۴۔ حکم، ۵۔ فعل، ۶۔ اتمام یا حاجت کا پورا کرنا یا معانی دیگر۔
اصطلاح میں قضاء ، افعال الٰہی جو کہ اس دنیا میں مخلوقات کی نسبت جاری ہوتے ہیں، کا نام ہے۔ قضاء و قدر کا مسئلہ عدل الٰہی کے باب میں نہایت اہم اور دقیق مسئلہ ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے چونکہ یہ خدا کے اسرار میں سے ایک راز ہے جس کو اہل راز ہی سمجھ سکتےہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:
طریق مظلم فلا تسلکوہ و بحر عمیق فلا تلجوہ و سر اللہ فلا تتکلّفوہ([5])؛ یہ ایک اندھیرا راستہ ہے اس پر نہ چلو اور گہرا سمندر ہے اس میں داخل نہ ہو اور یہ اللہ کا راز ہے اس کو کشف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔
مخفی نہ رہے کہ کلی طور پر قضاء و قدر کے بارے میں ہر مسلمان اعتقاد رکھتا ہے۔ اختلاف اس کی تفسیر میں ہے یہی وجہ ہے کہ جبری ٹولہ نے غلط خیال کیا ہے اور قضاء و قدر کے عقیدہ کو جبری عقیدہ کےمساوی قرار دیا ہے کہ ہر انسان کی سرنوشت قضاء وقدر الٰہی کی وجہ سے ازل سے معین ہے جو نیک ہے وہ نیک رہے گا جو برا ہے وہ برا رہے گا وہ نیک نہیں ہوسکتا جو فقیر ہے وہ قضاء و قدر کی وجہ سے فقیر ہے وہ فقیر ہی رہے گا۔ جو جاہل ہے وہ قضا و قدر کی وجہ سے جاہل ہی رہے گا، مطیع جبراً مطیع ہے اور عاصی جبراً عاصی ہے۔ مومن تقدیر الٰہی کی وجہ سے مومن ہے اور کافر قضا ء حتمی کی وجہ سے کافر ہے۔
حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے، چونکہ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہو تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان اپنے افعال میں مجبور ہو تو پھر بعثت انبیاء ، آسمانی کتب کا نزول اور امتحان یہ سب چیزیں بے مقصد ہوجاتی ہیں۔ بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں (اللہ کی قدرت کے ساتھ) خود مختار ہے یعنی نہ عقیدہ جبر صحیح ہے اور نہ ہی عقیدہ تفویض([6]) بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ امرٌ بین الامرین ہے۔ یعنی جبر اور تفویض کی درمیانی صورت صحیح ہے کما فی الروایات۔
تقریب ذہن کے لیےمثال: اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے عقل بھی عطا کی اور طاقت بھی عطا کی ہے۔ (بعبارت دیگر) دیکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، کھانے پینے کی طاقت وغیرہ وغیرہ عطا کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طاقت کا استعمال غلط کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے نہ کہ وہ اس طاقت کے استعمال میں مجبور محض ہے اگر کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے اللہ نے تو اِسے قتل سےمنع فرمایا ہے۔ طاقت تو اللہ نے ہی دی ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں وہ مجبور نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی سے اگر ایسا کرتا ہے تو جہنم کا مستحق ہوجائے گا۔
دیکھنے کی طاقت تو اللہ نے ہی دی ہے اب اگر کوئی اس کو غلط استعمال کرے، کسی نامحرم کی طرف شہوت کی نگاہ کرے تو یہ اپنی مرضی سے کررہا ہے۔ اس نگاہ کرنے میں وہ مجبور نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے ہی دیکھنے کی طاقت دی ہے اگر وہ چاہے تو اس وقت اس سے بصارت کو چھین سکتا ہے لیکن وہ اس کی بصارت کو نہیں چھینتا اس لیے کہ وہ بندے کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اس بصارت کا استعمال صحیح کرے یا غلط۔ اگر چاہے تو ایسی نگاہ نہ کرے یہی وجہ ہےکہ روایات میں ہے اگر کوئی شخص بری نگاہ سے اپنی آنکھوں کو بچالے تو اللہ اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔
عقیدہ جبر کی تبلیغ اور ترویج میں زیادہ عمل دخل بنی امیہ اور عباسی حکمرانوں کا تھا جو اپنی سیاہ کاریوں کو اس طریقے سے چھپانا چاہتے تھے کہ ہم تو مجبور ہیں جو کچھ ہم سے ہوا ہے یہ اللہ نے ہی کروایا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ کئی وجوہ سے باطل ہے کما مرّ۔
تذکر: مخفی نہ رہے کہ قضا ء و قدر کی دو قسمیں ہیں ۔ ۱۔ قضاء تکوینی، ۲۔قضاء تشریعی۔ پھر ان میں ہر ایک کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ حتمی، ۲۔ معلقی۔
قضا ءتکوینی: وہ افعال جو ذاتاً مصلحت رکھتے ہوں اس طرح کے افعال قابل تغییر نہیں ہیں ضرور واقع ہوتے ہیں۔
قضاء معلقی: وہ اشیاء و افعال جن کا حاصل ہونا کسی چیز کے ساتھ مشروط ہو مثلاً بلا کا ٹل جانا صدقہ کے ساتھ مشروط ہے یا طول عمر، صلہ رحمی کے ساتھ مشروط ہے ان امور کو بدائیات کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔
قضاء تشریعی: وہ حتمی اوامر اورنواہی شرعی جن میں دائمی مصلحت یا مفسدہ پایا جاتا ہے زمانہ کے اختلاف کے ساتھ تغییر نہیں کرتے۔
قضاء تشریعی معلقی: وہ اوامر و نواہی شرعی ہیں جو زمانہ اور مکلفین کے اختلاف کے ساتھ تغییر پیدا کرجاتے ہیں جن کو نسخ سے بھی تعبیر کرتےہیں۔
قدر
قدر کے بھی کئی معنی ذکر ہوئے ہیں: ۱۔ اندازہ و مقدار، ۲۔ عظمت و شرافت، ۳۔ اقتدار، توانائی، طاقت و قوت۔ ان کو قدرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ۴۔ کتابت، ۵۔ بیان و اخبار۔
اصطلاح میں قدر، ہر چیز کی حدّ اور اندازہ جس کے مطابق سب امور واقع ہوتے ہیں ، کا نام ہے۔ اور اس کی برگشت علم کی طرف ہوتی ہے یعنی خداوند متعال اشیاء کی حدود اور مقادیر کا عالم ہے۔تو اس بناء پر یہ صفات ذات سے ہوجائے گی۔
بدا
بدا کا لغت میں معنی مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا ہوتا ہے۔
اصطلاح میں بھی یہی معنی ہے کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا بعد اس کے کہ پہلے وہ ظاہر نہیں تھی۔
انسانوں کے افعال میں بداء کا منشاء
انسان کے افعال میں بدا کا منشاء یا انکی جہالت ہے یا عاجز ہونا یا سفاہت ہے۔،
انسان، چونکہ امور کے مصالح و مفاسد پر احاطہ نہیں رکھتا لہذا یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی کام کو اس میں مصلحت سمجھ کر شروع کرتا ہے کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کے ضرر کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہذا پشیمان ہوکر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یاکسی کام کو شروع کرتا ہے لیکن اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دووسرے کاموں میں مشغول ہوجاتا ہے۔
اہل سنت نے بدا کے اس معنی کو جو کہ عام بندوں کے افعال سے مربوط ہے کو ملحوظ رکھتےہوئے حق تعالیٰ کے بارے میں بدا کے منکر ہوگئے ہیں۔
حالانکہ افعال الٰہی میں بدا کا یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ اور معنی مراد ہے۔ جس سے نہ جہالت لازم آتی ہے نہ ہی عجز و سفاہت۔
اور اس کی دلیل یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال (کام) حکم اور مصلحت کی بناء پر ہیں حکمتیں اور مصلحتیں بدلتی رہتی ہیں اور غالباً تغیر کامنشاء لوگوں کے حالات ، صفات اور اخلاق ہیں جن کی وجہ سے مصلحتیں بدلتی رہتی ہیں۔
مثلاً صلہ رحمی سے زندگی طولانی ہوجاتی ہے۔قطع رحمی سے زندگی کم ہوجاتی ہے۔ عبادت، نعمت کا موجب بنتی ہے اور معصیت، بلاؤں کا موجب بنتی ہے۔ اس طرح جب لوگوں کے حالات مختلف ہوجائیں تو اللہ بھی ان کے حالات کے مطابق رفتار کرتا ہے (اگرچہ اللہ انسان کے حالات کو پہلے سےجانتاہے)
{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }([7])۔
خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کرلے۔
{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}([8])
اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کردیں گے اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔
{ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}([9])۔
پھر اگر وہ (یونس) تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی (مچھلی) کے شکم میں رہ جاتے۔
جس طرح طبیب مریض کے علاج میں اس کے حالات اور مرض کو مدنظر رکھتے ہوئے دوا کو تبدیل کرتا ہے اگرچہ جانتا ہے کہ یہ حالات اورمراتب مریض کو عارض ہوں گے لذا۔ اس کے مرض کے مطابق دوائی کو تبدیل کرتا ہے۔
لہذا بدأ، حق تعالیٰ کے افعال میں نہ توجہل کا موجب بنتا ہے نہ ہی عجز و ناتوانی اور نہ ہی سفاہت کا موجب بنتا ہے،خدا ازل سے ابد تک سب مقتضیات کا عالم تھا اور ہے۔ اورمقتضی کے موقع میں ہر فعل کے انجام پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے بندوں کے حق میں بدا کا معنی ظہور بعد از خفا ہے اور حق تعالیٰ کے حق میں اظہار بعد از اخفاء ہے یعنی کسی چیز کو چھپانے کے بعد اس کو آشکار کرنا ہے۔
خلاصہ یہ کہ بدا کا لغوی معنی جس سےجہل لازم آتا ہے وہ حق تعالیٰ کے بارے میں اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کے بارے میں ہرگز بداء سے یہ معنی، شیعہ کی مراد نہیں ہے۔ اب اگرکوئی جان بوجھ کر تعصب سے کام لے اور شیعہ پر تہمت لگائے تو قیامت کے دن ضرور اس سے پوچھا جائے گا۔
بدا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اور بد اعمال کی وجہ سے اپنے مسیر (راستے) کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اور خدا کے لیے دو تقدیریں ہیں ایک تقدیر مطلق ہے اور ایک تقدیر مشروط ہے۔ تقدیر مشروط میں انسان تاثیر پر قادر ہے۔ مثلاً اگر صدقہ دے دے تو وہ بلا جو نازل ہونا تھی وہ ٹل جائے گی۔ اور اللہ ازل سے تقدیر کی دونوں قسموں کا عالم ہے اور شرط کے وقوع اور عدم وقوع کا بھی عالم ہے۔ اور خدا کا یہ علم، انسان کے اختیار کے سلب کا موجب بھی نہیں ہے۔
سورہ رعد کی آیت ۳۹{ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب([10]) اسی کے پاس ہے۔ کی تفسیر کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا ﷺ سے سوال کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:
میں آپ کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں خدا کی راہ میں صدقہ دینا،ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا، بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کردیتا ہے۔ زندگی طولانی ہوجاتی ہے اور بری موت سے بچنے کا سبب بھی ہے۔([11])
مخفی نہ رہے کہ بدا کے مفہوم پر تمام اسلامی فرقے اعتقاد رکھتے ہیں اگرچہ بعض شبہات کی وجہ سے لفظ بدا سے گریز کرتے ہیں حالانکہ اس لفظ بدا کو رسول خدا ﷺ نے استعمال فرمایا ہے۔ بد اللہ عزوجلّ ان یبتلیہم([12])؛ خدا کو بدا ہوا کہ ان کو مبتلا کرے (آزمائے)
نیز دینی پیشوا چونکہ لوگوں کی عقل کے مطابق اور ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور عربی زبان میں رائج ہے کہ جو کوئی اپنا فیصلہ بدلے وہ کہتا ہے بَدَالِی، میرے لیے بدا واقع ہوا ۔ لہذا اس لفظ بدا کو خدا کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے اور خدا کے بارے میں بدا کا معنی: ابدا و اظہار بعد الاخفاء ہے (نہ کہ ظہور بعد از خفاء) مخفی نہ رہے کہ علم خدا میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
بدا پر اعتقاد رکھنےکی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ جو شخص بدا کا اعتقاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوف و رجا کی حالت میں رہتا ہے اور دعا، عبادت نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے کیونکہ خوف رکھنا، کہ ہوسکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا غلط کام ہوجائے جس کی وجہ سے نعمتیں سلب ہوجائیں اور بلاؤں کے نزول کا سبب بن جائے۔ لہذا اس خوف کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے۔
لیکن جو بدا کا منکر ہے وہ کہتا ہے : جف القلم بمام ہو کائن الی یوم القیامۃ؛ قلم خشک ہوگیا قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ ہوکر رہے گایعنی اعتقاد رکھتا ہے کہ جو مقدر ہوچکا ہے وہ ہوکر رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ دعا، عبادت اور دوسرے اعمال اس میں کچھ تاثیر نہیں کرسکتے۔
حالانکہ قرآن کی نص موجود ہے{ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}([13]) اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتاہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے (یعنی لوح محفوظ)
اور امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے اسی طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے حساب میں آسانی اور قضائے معلق و مشروط کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے۔ ([14])
امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتےہیں: صلۃ الرحمِ تُدِرُّ النِّعَمَ وَ تَدفَعُ النِّقَم؛ صلہ رحم نعمتوں کو بڑھانے اور سزاؤں کو دفع (دور) کرتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں : الصدقۃ تَستَدفِعُ البلاءَ و النِقّمَۃِ؛ صدقہ بلاؤں اور سزاؤں کو دور کر دیتا ہے۔
نیز امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتےہیں:بِالدُعاءِ تُصرِفُ البَلیَّۃ؛ دعا کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جاسکتا ہے۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: الدعاء ینفع مما نزل و ممّا لم ینزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء([15])؛ جو مصیبت وبلا نازل ہوئی ہے اور جو نازل نہیں ہوئی ان کے دور کرنے میں دعا فائدہ مند ہوتی ہے پس اللہ کے بندوں تم پر دعا لازمی ہے۔ (اور دعا کے ذریعہ اپنے سے بلاؤں کو دورکرو)
[1]۔سورہ نساء، آیت ۴۰۔
[2]۔سورہ نساء، آیت ۷۹۔
[3]۔سورہ روم، آیت ۴۱۔
[4]۔سورہ بقرہ، آیت ۱۵۵۔
[5]۔نہج البلاغہ، قصار کلمات ۲۸۷۔
[6]۔اہل سنت کا ایک گروہ تفویض کا قائل ہے کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے اور خدا کا ارادہ، انسانوں کے فعل میں کچھ مدخلیت نہیں رکھتا۔
[7]۔سورہ رعد، آیت ۱۱۔
[8]۔سورہ ابراہیم، آیت ۷۔
[9]۔سورہ صافات، آیت ۱۴۳- ۱۴۴۔
[10]۔یعنی لوح و محفوظ۔
[11]۔ملاحظہ ہو اہل سنت کی تفسیر در منثور سیوطی، ج۳/ ۶۶۔
[12]۔صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج۶، ص ۵۷۸،باب حدیث: ابرص و اعمی و اقرع فی بنی اسرائیل۔
[13]۔سورہ رعد، آیت ۳۹۔
[14]۔کافی، ج۲، ص ۴۷۰۔
[15]۔المستدرک حاکم، ج۱/ ۴۹۳۔
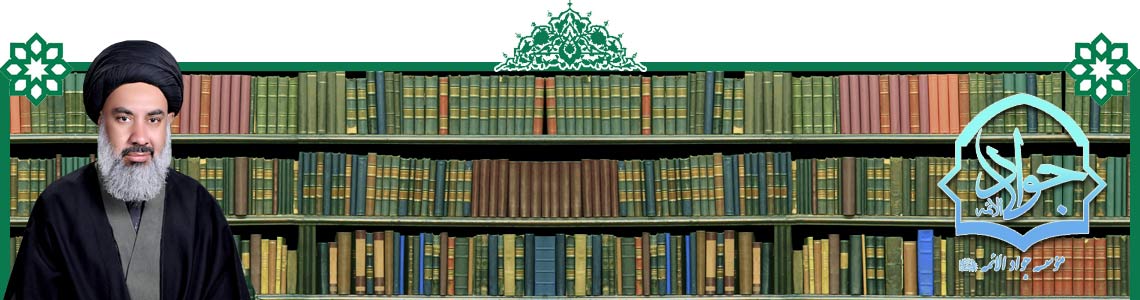 مؤسسه جواد الائمه علیه السلام
مؤسسه جواد الائمه علیه السلام